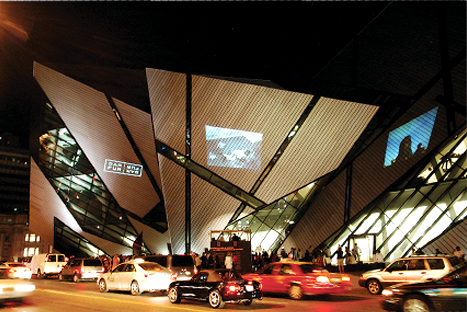وہ کون سا لمحہ تھا، جب میں نے اپنا دل جذبۂ تشکر سے لبریز پایا؟
شاید وہ لمحہ، جب ذہن کی راہ داریوں میں گردش کرتے خیال نے مجھے برقیاتی کتابت کے لیے تیار کیا، اور احساسات ’’کی بورڈ‘‘ پر انگلیوں کی حرکت کے وسیلے الفاظ کی شکل اختیار کرنے لگے۔ یا پھر ٹھیک یہ لمحہ، جب یہ سطریں لکھی جارہی ہیں۔ یا پھر میری زندگی میں در آنے والا ہر وہ لمحہ، جو برقیاتی کتابت کے لیے مختص ہوگا!
میری انگلیاں، اِس بیتتے لمحے ’’کی بورڈ‘‘ پر حرکت کر رہی ہیں۔ الفاظ خط نستعلیق میں، کمپیوٹر اسکرین پر ظاہر ہورہے ہیں۔ خط نستعلیق، جسے اردو کا چہرہ قرار دیا جاسکتا، جس سے اردو داں طبقہ محبت کرتا ہے۔
تو وہ کون سے لمحات ہیں، جب ممنونیت میری سماعتوں میں سرگرشیاں کرتی؟
شاید ہر لمحہ!
میرا دل جذبۂ تشکر سے لبریز ہے۔ میں ممنون ہوں، اس انسان کا، جس کی حیران کن ایجاد نے اِس حسین خط کو، جو کاتبوں کا محتاج تھا، وقت کا متقاضی تھا، برقیاتی دنیا سے، کمپیوٹر کی وسیع و عریض کائنات، ہم آہنگ کر دیا۔ مشین پر منتقل کر دیا۔ ورنہ شاید یہ خط مٹ جاتا، اردو بے چہرہ ہوجاتی۔
![]()
یہ احمد مرزا جمیل کی کہانی ہے، جنھوں نے برقیات (کمپیوٹر) کے میدان میں، خط نستعلیق میں، الفاظ کو باہم جوڑنے کی انوکھی ترکیب وضع کی۔ کمپیوٹر پر خط نستعلیق کو حقیقت کر دکھایا، جس سے اردو کتابت، طباعت اور خطاطی کی کایا پلٹ گئی۔ اِس بطل جلیل نے اب سے 32 برس قبل یہ کارنامہ انجام دیا۔ واضح رہے کہ اُس وقت مشینوں پر فقط خط نسخ میں اردو لکھی جاتی تھی۔ یہ خط خاصی جگہ گھیرتا تھا۔ اِس عمل کا اثر براہ راست لاگت پر پڑتا۔ ساتھ ہی پڑھت میں بھی دشوار تھا۔ خط نستعلیق قارئین کو زیادہ بھاتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ خط تھا، جس میں وہ اردو پڑھنا چاہتے تھے، مگر اس خط کا پیراہن زیب تن کرنے کے لیے اردو، بیسویں صدی کے اواخر میں بھی، جب مشینوں نے دنیا بدل ڈالی تھی، کاتبوں کی محتاج تھی۔ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونے میں ناکامی کے باعث اس پر معدومیت کا خطرہ منڈلانے لگا تھا۔ پھر منظر میں احمد مرزا جمیل کی آمد ہوئی، اور سب بدل گیا۔ ان کی شب و روز کی محنت کے نتیجے میں خط نستعلیق کو پر لگے۔ برقیاتی کتابت کا آغاز ہوا۔ آگے کی کہانی تاریخ کا حصہ ہے!
اردو کے اس محسن عظیم سے ملاقات کے لیے جب کراچی میں واقع اُن کی رہایش گاہ پر پہنچے، تو اِس 92 سالہ موجد کو حیران کن حد تک ہشاش بشاش اور صحت مند پایا۔ ہم ایک ایسے شخص کے روبرو تھے، جس کی یادداشت لڑکھرانے کی قائل نہیں تھی، جس کی حس مزاح ہنوز جوان تھی۔ گفت گو کا آغاز اُن کے حالاتِ زندگی سے ہوا۔ پھر اُن کے کارنامے پر تفصیلی بات ہوئی۔ اِس بابت وہ کہتے ہیں،’’نوری نستعلیق کی ایجاد سے خط نستعلیق کی دائمی حفاظت ہوگئی۔ اس کی تشکیل اور ترویج تو ترکوں اور ایرانیوں نے کی، اور پھر کتابت اور چھپائی کی دقتوں کی وجہ سے خیرباد بھی کہہ دیا، مگر اِسے زندہ ہم نے رکھا۔‘‘
نہیں۔ ’’ہم‘‘ نے نہیں۔ فقط احمد مرزا جمیل نے۔ بلاشبہہ!
آئیے، اِس نابغۂ روزگار کے دل چسپ اور حیران کن قصّے کا آغاز کرتے ہیں۔
شوق، جو وراثت میں ملاکہانی کا ابتدائیہ
یہ بٹوارے سے کئی برس پہلے کی بات ہے۔ دہلی کے مسلم اکثریتی علاقے، محلہ حویلی اعظم خان میں ایک مغل گھرانا آباد تھا، خوش نویسی جس کی شناخت تھی۔ اِس گھرانے میں 21 فروری 1921 کو ایک بچے کی پیدایش ہوئی، جس کا نام احمد مرزا جمیل رکھا گیا۔ اور یہی بچہ اِس کہانی کا مرکزی کردار ہے۔
جس گھر میں اُنھوں نے آنکھ کھولی، وہاں نقاشی اور خطاطی کے شاہ کار بکھرے تھے۔ اُن کے والد، نور احمد نے اپنے بڑے بھائی، حافظ محمد احمد کے حکم پر، جو جانے مانے خطاط تھے، فن خوش نویسی سیکھا۔ قطعہ نگاری کے ایک بڑے مقابلے میں کام یابی بھی اپنے نام کی، مگر اِس فن کو نور احمد نے بہ طور پیشہ نہیں اپنایا۔ رجحان اُن کا آرٹ کی جانب تھا۔ اسی میں دل چسپی تھی، اِسے ہی کیریر بنایا۔ ’’ہمدرد دواخانہ‘‘ کے مشہور شربت، روح افزا کا ’’لیبل‘‘ اُن ہی کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ 1922 میں اُنھوں نے لکڑی کا ایک ہینڈ پریس خریدلیا۔ اُسے ’’نور فائن آرٹ لیتھو پریس‘‘ کا نام دیا۔ وہاں پتھر سے لیتھوگرافک چھپائی ہوا کرتی تھی۔ کتابوں کے سرورق تیار ہوتے، رنگین طغرے بنائے جاتے۔ کاروبار دُرست سمت جارہا تھا کہ ہندو شراکت دار کی دغابازی نے سب سبوتاژ کر دیا۔ نور احمد بمبئی کوچ کرنے پر مجبور ہوگئے، جہاں یافت کے لیے انھوں نے خود کو فری لانسر آرٹسٹ اور لیتھو گرافر کے قالب میں ڈھال لیا۔
![]()
اِن معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نور احمد کی اولاد کو آرٹ میں دل چسپی وراثت میں ملی۔ خدا نے تین بیٹوں اور تین بیٹیوں سے اُنھیں نوازا تھا۔ احمد مرزا جمیل کا نمبر تیسرا تھا۔
ماضی بازیافت کرتے ہوئے کہتے ہیں،’’میرے بڑے بھائی، منظور احمد بہت اچھے آرٹسٹ تھے۔ اُنھوں نے قائداعظم کے کئی یادگار پورٹریٹ بنائے۔ قائد اعظم نے اُن کے ایک پورٹریٹ پر دست خط بھی کیے تھے، مگر وہ فن پارہ دہلی کے فسادات میں ضایع ہوگیا۔‘‘
یوں تو ان کے والد بہت حلیم انسان تھے، البتہ اصولوں کے معاملے میں انھوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اولاد کو باپ کے مزاج کا پتا تھا، کبھی ایسی حرکت ہی نہیں کی کہ سزا کی نوبت آتی۔ بچپن میں وہ خاصے کھلنڈرے ہوا کرتے تھے۔ کھیلوں میں آگے آگے رہے۔ کرکٹ کھیلی، اسکول کی ٹیم کے کپتان رہے۔ دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لیا۔
اور یوں بمبئی کی گلیاں اُن کی پرورش کرتی رہیں۔
گجراتی لازمی، جے جے آرٹ اسکول اور انعامات زمانہ تدریس کا…….
ایک علم وہ ہے، جو نصابی کتب میں چھپا ہوتا ہے اور ایک وہ، جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے۔ آخر الذکر تو باپ سے وراثت میں مل گیا، اول الذکر کے لیے اُنھیں درس گاہوں کا رخ کرنا تھا۔احمد مرزا جمیل کے تعلیمی سفر کا آغاز میونسپل کے اسکول سے ہوا۔ ایک سال کے بعد زکریا مسجد اسکول کا حصہ بن گئے، جہاں قرآن پاک، اردو، انگریزی اور گجراتی کی تعلیم حاصل کی۔
اُس زمانے میں چوتھی پاس کرنے کے لیے گجراتی لازمی تھی۔ پھر سینٹ جوزف ہائی اسکول، بمبئی کا رخ کیا، جہاں سے فورتھ اسٹینڈرڈ (ساتویں جماعت) کا مرحلہ طے کیا۔ اب بمبئی کے مشہور زمانہ، جے جے اسکول آف آرٹ میں داخلہ لے لیا۔ یہ فیصلہ قابل فہم تھا کہ آرٹ کا شوق بہ درجہ اتم موجود تھا۔ دس برس کی عمر سے وہ بمبئی آرٹ سوسائٹی کی نمایشوں میں حصہ لے رہے تھے۔
![]()
38ء میں وہ جے جے اسکول کا حصہ بنے، 45ء تک وہاں رہے۔ آخری دو برس فیلو شپ کی۔ زمانۂ طالب علمی میں یوں تو مصوری کے ہر شعبے کا تجربہ کیا، مگر زیادہ رجحان میورل پینٹنگ کی جانب تھا۔ کئی بڑے اعزازات اُسی عرصے میں اپنے نام کیے۔ اُن کی ایک ڈرائنگ نے 1942 میں Dolly Cursetji Mural Decoration مقابلے میں پہلا انعام اپنے نام کیا۔ اگلے برس ہونے والے ’’آل انڈیا آرٹ ان انڈسٹری ایگزی بیشن‘‘ میں اُن کی اکلوتی انٹری تین اعزازات کی حق دار ٹھہری۔ 44ء میں ہونے والے اِسی مقابلے میں ان کی پینٹنگ نے پہلا انعام حاصل کیا۔ الغرض زمانۂ طالب علمی ہی میں خود کو بہ طور آرٹسٹ منوا لیا۔
اب احمد مرزا جمیل نئے میدانوں کا رخ کرنے کے لیے تیار تھے۔
روزے رکھنے والا ہندو اور ’’دیوداس‘‘ کا خالق فلم نگری کی یادیں
وہ خوابوں سی حسین دنیا تھی، پر خواب نہیں تھی۔ حقیقی تھی۔
بمبئی فلم نگری سے ان کا تعلق تراب اسٹوڈیو کے مالک، محمد تراب کے وسیلے قائم ہوا۔ اُنھوں نے احمد مرزا جمیل کا تعارف ’’چوہدری جی‘‘ کے نام سے معروف ایک فلم ڈائریکٹر سے کروایا، جنھوں نے 23 سالہ نوجوان آرٹسٹ کو اپنی فلم کے سیٹ اور ملبوسات ڈیزائن کرنے کی ذمے داری سونپ دی۔
تین ماہ وہ اس کام میں جٹے رہے۔ ایک دن ڈائریکٹر صاحب سے پوچھا: ’’کچھ پیسے ویسے بھی ملیں گے!‘‘ ڈائریکٹر نے منشی کو بلوا کر پچاس روپے تھما دیے۔ یہ پہلا معاوضہ تھا، وہ بھی تین ماہ کا۔ البتہ وہاں بہت کچھ سیکھا۔
اُن ہی دنوں بمبئی کے ایک صاحب، باسودیو پرساد سہنا نے ایک فلم ’’ایران کی ایک رات‘‘ پروڈیوس کرنے کا ارادہ باندھا، تو اُنھیں بہ طور آرٹ ڈائریکٹر کولکتا چلنے کی پیش کش کر دی۔ اُنھوں نے اس انوکھے تجربے سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ آرٹ ڈائریکشن پر دست یاب کتب کا مطالعہ کیا، اور باسو دیو سہنا کے ساتھ کولکتا روانہ ہوگئے۔ وہاں رہایش سہنا صاحب ہی کے بنگلے میں تھی۔ بتاتے ہیں،’’وہ ہندو تھا، مگر میرے ساتھ رمضان کے تیس روزے رکھا کرتا۔ ہم دونوں بغیر سحری کا روزہ رکھتے تھے، اور مغرب کے وقت ساتھ افطاری کرتے۔‘‘
![]()
معروف اداکار اور ’’دیوداس‘‘ کے ہدایت کار، پی سی بروا کی ڈائریکشن میں بننے والی ’’ایران کی ایک رات‘‘ کا سیٹ، کاسٹیومز اور پوسٹر ڈایزئن کرنے کی ذمے داری ان کے کاندھوں پر تھی۔ پی سی بروا کے معیار پر پورا اترنا سہل نہیں تھا، مگر انھوں نے لگن اور محنت سے یہ ممکن کر دکھایا۔ آنے والے عرصے میں چند اور فلموں میں کام کیا۔
پھر کولکتا میں سہنا صاحب اور ان کی بیوی، ساوتری دیوی کے ساتھ فلم پبلی سٹی اسٹوڈیو ’’مووی آرٹس‘‘ کھول لیا۔ فروری 50ء میں جمیل صاحب، بگڑتے حالات سے دل برداشتہ ہو کر پاکستان چلے آئے۔ یہ اسٹوڈیو اب بھی کولکتا میں موجود ہے۔
خاندان کبھی بمبئی لوٹ نہیں سکا داستانِ ہجرت
بٹوارے کے دن، وہ دن جو کچھ برس بعد اردو فکشن کا اہم ترین موضوع بننے والے تھے، اُنھیں خوب یاد ہیں۔ ہاں، تب ماحول میں تناؤ تیرا کرتا تھا، سناٹے میں خوف کی چاپ سنائی دیتی۔
یہ 1947 کے وسط کا ذکر ہے۔ بہن کی شادی کے سلسلے میں اہل خانہ کے ساتھ احمد مرزا جمیل کا دہلی جانا ہوا، جہاں فسادات پھوٹ پڑے۔ ان کا خاندان بمبئی لوٹ ہی نہیں سکا۔ حالات میں سدھار آنے تک بمبئی کا مکان چند دوستوں کو امانتاً سونپ دیا، جنھوں نے امانت میں خیانت کرنا ضروری خیال کیا، اور مکان پر قبضہ جما لیا۔ کسی نہ کسی طرح وہ تو دہلی سے کولکتا چلے گئے، مگر خاندان دہلی ہی میں رہا۔ بعد میں جب وہ اپنے فن پارے لینے بمبئی پہنچے، تو وہاں کے خرابے میں سب ضایع ہوچکا تھا۔ کچھ نہیں بچا تھا۔ اِس واقعے نے دل توڑ دیا۔ رنگوں سے وہ دور ہوگئے۔ بعد میں جب کبھی کینوس کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ ہی منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔
![]()
حالات کے جبر نے خاندان کو پاکستان کی سمت دھکیل دیا، جو راول پنڈی اور لاہور سے ہوتا ہوا کراچی پہنچا۔ البتہ گھر والوں کی مالی معاونت کے لیے جمیل صاحب کو کولکتا ہی میں ٹھہرنا پڑا۔ کولکتا خود کشیدگی کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، مگر حالات میں سدھار کا کوئی امکان ظاہر نہیں ہوا۔ ہاں، بگاڑ کے نشانات واضح ہوتے گئے۔ مجبوراً تقسیم کے تین برس بعد وہ بھی کراچی چلے آئے۔
’’وکیل گودام لے کر کیا کرے گا؟
پیشہ ورانہ سفر کا جائزہ
نیا ماحول، نئے لوگ، نئی زندگی!
اس نئی دنیا میں معاشی مسئلہ سب سے قوی تھا۔ کراچی پہنچتے ہی اُنھوں نے ملازمت کی تلاش شروع کردی۔ تجربے سے لیس تھے، اِس لیے یہ مرحلہ دشوار ثابت نہیں ہوا۔ جلد ہی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں، 500 روپے ماہ وار پر بہ طور آرٹ ڈائریکٹر ذمے داریاں سنبھالی۔ اُن ہی دنوں قائداعظم کا وہ شہرۂ آفاق اسکیچ بنایا، جو گذشتہ چھے عشروں سے ری پرنٹ ہورہا ہے۔ اس اسکیچ کو معروف آرٹ کریٹک، مارجری حسین نے شاہ کار قرار دیا تھا۔
ڈیڑھ برس بعد اس ادارے سے الگ ہو کر اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، جلد ہی جس کا شمار صف اول کی پرنٹنگ کمپنیوں میں ہونے لگا۔
اپنی کمپنی شروع کرنے کا خیال کیوں کر سوجھا؟ یہ سوال اُنھیں ماضی میں لے جاتا ہے، جب کراچی میں ایک ایسی پرنٹنگ مشین کا چرچا تھا، جسے فقط ڈیزائن دینے کی ضرورت ہوتی، بلاک وغیرہ نہیں بنائے جاتے تھے۔ انھوں نے جب اُس کے متعلق سنا، تو خواہش ہوئی کہ یہ مشین دیکھی جائے۔ برنس روڈ پر واقع ایک ادارہ یہ مشین فروخت کر رہا تھا۔ ایک روز دفتر سے اٹھے، اور وہاں پہنچ گئے۔ پتا چلا کہ یہ ’’روٹا پرنٹ مشین‘‘ کہلاتی ہے۔ اس کی بابت کیے جانے والے دعویٰ سو فی صد درست تو نہیں، مگر اُن میں تھوڑی بہت صداقت ضرور ہے۔ خیال آیا، اُن کے والد اور بھائی کے آرٹ ورک کو مختلف پبلشرز نے چھاپ کر خوب کمایا، کیوں نہ خود یہ کام کیا جائے۔
51ء میں پندرہ ہزار روپے میں انھوں نے یہ مشین خرید لی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اِسے لگایا کہاں جائے۔ کراچی میں اس زمانے میں گھروں وغیرہ کی الاٹمنٹ ہورہی تھی۔ وہ بھی ’’ریفیوجی ری ہیبیلی ٹیشن ڈیپارٹمنٹ‘‘ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں،’’میں ڈائریکٹر سے ملا۔ اس عہدے پر تعینات شخص نہ جانے کتنا کما سکتا تھا، مگر جو صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، اُن کے کپڑوں میں پیوند لگے تھے۔ ان کی شخصیت کے اس پہلو نے مجھے بہت متاثر کیا۔ خیر، میں نے مدعا بیان کیا۔ گو کوئی خالی پلاٹ نہیں تھا، مگر جب میں نے اپنے چھاپے ہوئے قائد اعظم کے، پوسٹ کارڈسائز کے پینسل اسکیچ پیش کیے، تو وہ چھپائی اور معیار دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور ایک وکیل کے نام الاٹ ہونے والے گودام کو یہ کہتے ہوئے؛’وکیل بھلا گودام لے کر کیا کرے گا؟‘ وہ 16×22 فٹ کی جگہ مجھے سونپ دی۔‘‘
![]()
کسٹم ہاؤس کے سامنے، بوہری روڈ پر واقع اس گودام کی کچی دیواروں کو پکا کرنے، زمین کے گڑھے بھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ الیٹ پبلشرز کے پرچے تلے، دو ملازمین کے ساتھ انھوں نے کام شروع کیا۔ جب یہ خبر پھیلی کہ احمد مرزا جمیل نے اپنا پرنٹنگ پریس لگا لیا ہے، تو آرڈرز کا تانتا بندھ گیا۔ چھے ماہ کا کام جمع ہوگیا۔
آنے والے دن مصروفیات سے بھرپور تھے۔ شب و روز ایک کر دیے۔ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا۔ کئی برس تک اتوار کی چھٹی نہیں کی۔ دھیرے دھیرے دفتر پھیلنے لگا۔ ملازمین کی تعداد بڑھ کر 150 ہوگئی۔ 61ء میں ان کا ادارہ سائٹ ایریا منتقل ہوگیا۔ آنے والے چند برسوں میں الیٹ پبلشرز لمیٹڈ نے پرنٹنگ کی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ بہتوں نے ان کے ادارے میں تربیت حاصل کی، اور بعد میں پاکستان اور بیرون ملک اپنے پریس لگائے۔ 90 کی دہائی کے اوائل میں خود کو ان جھمیلوں سے الگ کرکے بچوں کو ذمے داری سونپ دی۔
![]()
اندیشوں نے گھیر لیا، راتوں کی نیند حرام ہوگئی، جب اردو تاریخ کا اہم ترین واقعہ رونما ہوا
خط نسخ کی برقی مشینوں سے دوستی پرانی تھی، مگر اردو قاری خط نستعلیق کے عشق میں مبتلا تھے، جو ہنوز خود کو مشین سے ہم آہنگ نہیں کرسکا تھا۔ کاتبوں کی جنبش قلم کا محتاج تھا۔ کتابوں کی اشاعت میں برسوں لگ جاتے کہ لازم تھا، پوری کتاب ایک ہی کاتب لکھے۔ تصحیح کی ضرورت پیش آتی، تو پورا صفحہ دوبارہ لکھا جاتا، مگر یہ صورت حال ہمیشہ نہیں رہنے والی تھی۔ تبدیلی کا آغاز ہونے کو تھا۔
جمیل صاحب ایک پبلشر تھے۔ اردو لکھاری اپنی کتابوں کی اشاعت کا ارادہ لیے ان سے ملنے آتے۔ جواب میں وہ کہتے،’’کتابت کروالیں، میں چھاپ دوں گا، مگر کتابت اچھی ہونی چاہیے۔‘‘ کوئی چھے ماہ بعد لوٹتا، کوئی ڈیڑھ سال بعد۔ اور جو کتابت ہوتی، اس سے وہ خود کو مطمئن نہیں پاتے تھے۔
![]()
ان ہی دنوں ایک انگریز سے ملاقات ہوئی، جو پرنٹنگ مشین فروخت کیا کرتا تھا۔ اس نے تیکنیکی مسائل کا حل، خط نستعلیق تج کر، ترکوں اور ایرانیوں کی طرح خط نسخ یا رومن اسکرپٹ میں تلاش کرنے کا مشورہ دیا۔ جواب میں اُنھوں نے کہا،’’انگریزوں نے دوسو برس برصغیر پر حکومت کی، جب اُس وقت تم ہمارا خط نہیں بدل سکے، تو اب کیا بدلو گے!‘‘
پرنٹنگ انڈسٹری کی معروف شخصیت، سید مطلوب الحسن اُن کے دیرنیہ دوست تھے۔ دونوں کے درمیان خط نستعلیق کو ’’میکانائز‘‘ کرنے کا مسئلہ زیربحث رہتا۔ ’’فوٹو ٹائپ سیٹنگ مشین‘‘ انھوں نے 62ء میں خریدی تھی، جس کے آٹھ سو خانوں میں فلمیں لگی ہوتیں۔ اِسے ماضی میں اُنھوں نے برقیاتی کتابت کے ارادے سے برتا تھا۔ خط نسخ تو ہاتھ آگیا، مگر خط نستعلیق دور کھڑا مسکراتا رہا۔ اندازہ ہوا کہ فلموں سے کام نہیں بنے گا۔ حروف کے ٹکڑے کرنے کے بجائے الفاظ کے ٹکڑے کیے جائیں۔ کیوں نہ یونٹ بنا دیے جائیں۔ یعنی ’’پر‘‘ لکھنے کے لیے ’’پ‘‘ اور ’’ر‘‘ کو الگ نہ کیا جائے، بلکہ ’’پر‘‘ ہی کا یونٹ بنایا جائے، جو ہر جگہ کام آئے۔ بہ قول اُن کے،’’یہ خیال مجھے قابل عمل لگا۔ جیسے ’فر‘ ایک یونٹ ہے۔ اس کے آغاز میں ’کا‘ لگا دیا جائے، تو ’کافر‘ ہوجا ئے گا۔ آخر میں ’حت‘ لگا دیں، تو ’فرحت‘ ہوجائے گا۔‘‘ دونوں دوست اس کلیے پر متفق تھے، مگر اس کا عملی تجربہ چاند کے سفر سا دشوار تھا۔
![]()
نومبر 79ء میں ان کا سنگاپور جانا ہوا، جہاں پرنٹنگ انڈسٹری کی ایک بڑی نمایش ہورہی تھی۔ وہاں مونوٹائپ کارپوریشن کے اسٹال پر رش لگا دیکھا۔ تجسس انھیں اسٹال تک لے گیا۔ پتا چلا کہ چینی زبان کمپوز ہورہی ہے۔ میز پر ’’کی بورڈ‘‘ رکھا ہے، جس میں چھے سات سو بٹن ہیں۔ آپریٹر ایک ایک بٹن دبا رہی ہے، اسکرین پر لفظ ابھر رہے ہیں، جو جُڑ کر ایک شکل اختیار کر لیتے۔
وہ ایک قیمتی لمحہ تھا۔ ایک حوصلہ افزا خیال ذہن میں کوندا۔ بہ قول اُن کے،’’میں نے خود سے کہا؛ چینی میں 80 ہزار کریکٹرز ہیں، جب اُنھوں نے80 ہزار اشکال قابو کرلیں، تو ہم کیوں نہیں کرسکتے۔ بس، اﷲ نے احسان کیا۔ جتنے پردے ذہن پر پڑے تھے، اٹھتے گئے۔ مونوٹائپ کارپوریشن کے سیلز مینیجر، مسٹر ڈیرک کارکیٹ وہاں موجود تھے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے انھیں کراچی آنے کی دعوت دی۔ انھوں نے جواب دیا؛ ’میں ابھی پاکستان ہی سے آرہا ہوں۔ ہم نے اسی مشین پر مقتدرہ کو ایک سسٹم بنا کر دیا تھا، جسے رد کر دیا گیا، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ ہمارا بہت نقصان ہوا۔‘ میں نے یہ کہہ کر انھیں قائل کر لیا کہ اگر ہمارا تجربہ ناکام گیا، تو مالی نقصان میں اکیلا برداشت کروں گا۔‘‘
![]()
جوں ہی لندن میں بیٹھے مونوٹائپ کے ڈائریکٹر، مسٹر جان مال نے اپنی رضامندی ظاہر کی، جمیل صاحب اِس منصوبے میں جٹ گئے۔ اردو کے ایک موقر روزنامے کا لاہور سے اجرا ہونے کو تھا۔ جب اخبار کے مالک کو اطلاع ملی کہ خط نستعلیق کو کمپیوٹر پر منتقل کیا جارہا ہے، تو انھوں نے جمیل صاحب سے رابطہ کیا، اور کہا کہ وہ اپنے لاہور کے پرچے کو اِس منصوبے کی تکمیل تک موخر کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی کام میں معاونت کے لیے ایک کاتب ان کی طرف روانہ کردیا۔
پہلے نمونے کی تیاری میں چھے ماہ لگے، جس کے لیے کاتب نے پانچ ملی میٹر کے قلم سے 154 یونٹ لکھے۔ 80ء کے موسم خزاں میں شہر لندن میں ہونے والی نمایش کے دوران مونو ٹائپ نے یہ نمونہ پیش کیا۔ وہاں موجود ایرانیوں اور افغانیوں نے تو بہت پسند کیا، البتہ پاکستانیوں نے شک کا اظہار کیا۔ پاکستان میں بھی ہر دوسرا شخص خط نستعلیق کے برقی مشین سے ہم آہنگ ہونے کے دعوے کو ڈھکوسلا قرار دیتا نظر آیا، مگر جمیل صاحب کو پروا نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سرنگ کے دہانے پر روشنی ہے۔کراچی لوٹنے کے بعد وہ اس منصوبے میں شریک اپنے رفیق، سید مطلوب الحسن کے ساتھ مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین، اشتیاق حسین قریشی سے ملے، اور اپنے چھپے ہوئے نمونے پیش کیے۔ آئیڈیا اشتیاق قریشی کے دل کو لگا۔ انھوں نے اِسے مقتدرہ کے پلیٹ فورم سے پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ساتھ ہی کہا کہ وہ صدر پاکستان سے ملاقات کے لیے جارہے ہیں، یہ نمونہ وہ اُن کے سامنے پیش کریں گے۔
![]()
جمیل صاحب کہتے ہیں،’’اشتیاق صاحب دہلی میں جنرل ضیاء الحق کے استاد رہ چکے تھے۔ ضیا الحق ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ صدر صاحب سے اِس منصوبے کے لیے درآمد کی جانے والے پہلی دس مشینوں کی ڈیوٹی ضرور معاف کروالیں۔ دراصل ایک مشین کی قیمت 40 لاکھ تھی، اتنی ہی اس پر ڈیوٹی تھی۔ کُل ملا کر ایک مشین پر 80 لاکھ لاگت آرہی تھی۔ خیر، صدر صاحب نے ان سے پہلا سوال تو یہی کیا کہ اس دعوے میں کوئی جان ہے بھی یا نہیں؟ دراصل اِس سوال کے پیچھے نظام حیدرآباد کی وہ ہی فکر کارفرما تھی کہ خط نستعلیق کو مشین پر منتقل کرنا ممکن نہیں۔ انھوں نے بھی تقسیم سے قبل اس ضمن میں کوششیں کی تھیں، جو ثمر آور ثابت نہیں ہوئیں۔‘‘
حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کے بعد مقتدرہ قومی زبان نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں خط نستعلیق کی برقیاتی کتابت میں کام یابی کا اعلان کیا گیا۔ ابتدائی نمونے دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور اس دل کش خط کی کمپیوٹر کے ذریعے کتابت کی امید بڑھنے لگی۔
![]()
چند روز بعد برطانوی ماہرین کے ساتھ لندن میں جمیل صاحب کی میٹنگ ہوئی۔ زیربحث سوال یہ تھا کہ منصوبہ کب تک مکمل ہوسکتا ہے؟
بہ قول اُن کے،’’میٹنگ میں موجود ایک انگریز نے کہا کہ کیلی گرافی میں پونے انچ کے قلم سے یونٹ لکھے جائیں گے، 10×10 انچ کا کاغذ ہوگا۔ کتابت کا مرحلہ آتے آتے پانچ برس لگ جائیں گے۔ پھر ڈیجیٹائزنگ کے ماہر نے کہا؛ ہمارا کام ڈیڑھ سال کا ہے۔ اگر ہم شفٹ بڑھادیں، تو چھے ماہ میں بھی مکمل کرسکتے ہیں۔ میں نہ صرف ایک آرٹسٹ تھا، بلکہ پبلشنگ اور ماس پروڈکشن کا بھی وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی چھے ماہ میں منصوبہ مکمل کرلیں گے۔ اس وقت خیال یہی تھا کہ بیس کاتب اکٹھے کروں گا، اور تختیاں لکھوا لوں گا۔ بعد میں خیال آیا کہ بیس کاتب، بیس مختلف اساتذہ کے شاگرد ہوں گے۔ ہر ایک اپنے طرز پر تختی لکھے گا۔ تحریر میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ ہم نے ایک کاتب کو بلوایا، جس نے ایک دن میں پچاس تختیاں لکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جب اسے بتایا کہ پونے انچ کے قلم سے 10×10 انچ کے کاغذ پر لکھنا ہے، تو وہ پچاس سے یومیہ پانچ تختیوں پر آگیا۔ کمپیوٹر کی شرائط بتائیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔‘‘
امکانات معدوم ہونے لگے۔ اندیشوں نے گھیر لیا۔ راتوں کی نیند حرام ہوگئی۔ کہتے ہیں،’’جنرل ضیاء الحق سے ہماری بات ہوچکی تھی، ملکی اور غیرملکی میڈیا میں اس ایجاد کا تذکرہ آچکا تھا، مگر اب آگے بڑھنے کے تمام راستے مسدود ہوگئے۔ وہ بڑا سخت وقت تھا۔ پھر سید مطلوب الحسن، اﷲ بخشے اُنھیں، کہنے لگے؛ جمیل یہ کام تم خود کرو گے۔ میں نے کہا؛ اﷲ اﷲ کرو۔ میں آرٹسٹ ضرور ہوں، میرے تایا خوش نویس تھے، مگر یہ کام بالکل الگ ہے۔ اس پر انھوں نے کہا؛ پھر تو بڑی سبکی ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو میں نے اﷲ کا نام لے کر وہ کام شروع کیا۔ جتنا تجربہ تھا، سب یک جا کیا۔ رات دن ایک کردیے۔ اس زمانے میں مَیں چھے سات گھنٹے سے زیادہ گھر نہیں آتا تھا۔ گھر والے کہنے لگے تھے کہ بستر بھی آفس ہی میں لگالیں۔ میں نے چھے مہینے میں اٹھارہ ہزار تختیاں لکھ لیں۔ پہلے تختیوں کا نیگٹو بنتا، پھر پوزیٹو تیار ہوتا۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹیم بنائی۔ کمپیوٹر ک،م، ن تو نہیں جانتا۔ وہ تو نمبر جانتا ہے۔ تو ہم نے نمبروں کو یونٹ سے ہم آہنگ کیا۔‘‘
تجربہ کام یاب رہا۔ ان اٹھارہ ہزار تختیوں سے تین لاکھ سے زیادہ الفاظ بن سکتے تھے، جو الفاظ اس وقت رہ گئے، وہ مشین پر ٹائپ کرتے ہوئے نسخ میں ظاہر ہوتے، جن کی بعد میں کاتب تصحیح کرلیتے۔ والد، نور احمد کے نام پر اُنھوں نے اِس ایجاد کو ’’نوری نستعلیق‘‘ کا نام دیا۔ اور دنیا کے سامنے پیش کردیا۔
یکم اکتوبر 81ء کو جب لاہور سے اردو کے اُس موقر روزنامے کا اجرا ہوا، تو وہ نوری نستعلیق ہی میں تھا۔ کہتے ہیں،’’ہم نے بغیر کسی آزمایش اور تجربے کے یہ کام کیا۔ اور اﷲ کا کرم ہے کہ اخبار ایک دن بھی کمپوزنگ کی وجہ سے غیرحاضر نہیں ہوا۔‘‘
اردو کتابت اور طباعت کی دنیا میں انقلاب آچکا تھا۔
کون اکڑوں بیٹھ کر کتابت کرے گا؟
نوری نستعلیق کے بعد کی دنیا
وہ ایک عظیم تبدیلی تھی، جس سے مزید حیران کن تبدیلیاں جنم لینے کو تھیں!
جمیل صاحب کی ایجاد نے خط نستعلیق میں نئی روح پھونک دی۔ اردو پرنٹنگ کی دنیا بدل گئی۔ جس مشین کے ذریعے برقی کتابت کا آغاز ہوا تھا، وہ Slave کمپوزنگ مشین کہلاتی تھی۔ ابتدائی دس مشینوں پر صدرپاکستان نے وعدے کے مطابق ڈیوٹی معاف کر دی۔ ایجاد کا چرچا ہوا، تو مختلف ادارے ان سے رابطہ کرنے لگے۔ اخبارات اور کتابوں کی اشاعت کا عمل راتوں رات سہل ہوگیا۔ لاگت بھی گھٹ گئی، اور وقت بھی بچنے لگا۔
کچھ ہی برس گزرے ہوں گے کہ پرسنل کمپیوٹر کی منظر میں آمد ہوئی، جس نے انتہائی مختصر وقت میں مسند اقتدار سنبھال لی۔ جمیل صاحب کے بہ قول، کمپیوٹر کی آمد کے بعد Slave کمپوزنگ مشین ڈائناسور کے زمانے کی چیز لگنے لگی۔ جمیل صاحب کے مشوروں کی روشنی میں مونو ٹائپ کارپورشن نے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے خط نستعلیق کو پرسنل کمپیوٹر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سوفٹ ویئر کی تیاری شروع کی۔ 91-92 میں ’’نوری نستعلیق ان پیچ‘‘ کے نام سے یہ سوفٹ ویئر مارکیٹ میں آگیا۔ اور گذشتہ دو عشروں سے یہ اردو کتابت اور طباعت پر چھایا ہوا ہے۔ اِس ایجاد پر حملے بھی ہوئے۔ ایک اخبار کے دفتر سے اس کے ترسیمے چرائے گئے، جنھیں بعد میں مشین پر منتقل کرکے، ان پیج کی آمد سے قبل ایک سوفٹ ویئر بنایا گیا تھا، مگر وہ مسئلے کا مکمل حل نہیں تھا۔ سو ناکام گیا۔
اپنی ایجاد سے متعلق گفت گو کرتے ہوئے جمیل صاحب کہتے ہیں،’’اچھا کاتب بننے کے لیے پانچ چھے برس خرچ ہوتے تھے، جب کہ کمپیوٹر پر اسے سیکھنے میں ایک سے دو ہفتے لگتے ہیں۔ یعنی کام آسان ہوگیا۔ ایک کاتب میرے پاس آئے، اور کہا؛ میرا بچہ کام نہیں سیکھتا۔ میں نے کہا، اب آج کے دور میں کون نوجوان گھنٹوں اکڑوں بیٹھ کر کام کرے گا۔ اسے کمپوزنگ سکھاؤ۔‘‘
کتابیں سرہانے رکھی رہتی ہیں
زندگی کے چند گوشے
کب خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اِس سوال کا جواب دینا جمیل صاحب کے لیے سہل ہے۔ بہ قول ان کے، لوگوں کی مدد کرکے، ان میں اعتماد پیدا کرکے وہ مسرت محسوس کرتے ہیں۔ دُکھوں سے واسطہ کم ہی رہا۔ اپنوں کی جدائی نے کرب سے دوچار ضرور کیا، مگر اسے زندگی کا حصہ خیال کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنی مثال پیش کرتے ہوئے مسلسل کام، کام اور صرف کام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
پاکستان کے موجودہ حالات اُنھیں دُکھی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں،’’جب میں ہندوستان سے آرہا تھا، ایک ہندو نے مجھے سے کہا؛’تم مسلمانوں کا خون گرم ہے۔ یہاں تو ہم سے لڑتے رہتے ہو، وہاں جاکر کیا آپس میں لڑو گے؟‘ اور اس کی بات درست ثابت ہوئی۔ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا، مگر آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بندوقوں کے سائے میں نماز پڑھی جائے۔ یہ صورت حال افسوس ناک ہے۔‘‘
ہر صاحب ذوق کے مانند اچھے شعر اُنھیں بھی بھاتے ہیں، خصوصاً ایسے، جن سے رجائیت جھلکتی ہو۔ البتہ مصروفیات نے فکشن سے دور رکھا۔ اقبال بانو اور فریدہ خانم کی آواز اچھی لگتی ہے۔ کسی زمانے میں فلمیں بھی دیکھیں۔ دلیپ کمار کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ کتابیں سرہانے رکھی رہتی ہیں۔ جب وقت ملتا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ آپ بیتی لکھنے کا سوچا ضرور، مگر خود کو اس کام کے لیے مناسب خیال نہیں کرتے۔
49ء میں ان کی شادی ہوئی۔ کہتے ہیں، مصروفیات بہت رہی، مگر گھر والوں، خصوصاً بیگم کے تعاون کے طفیل کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ خدا نے انھیں تین بیٹوں، دو بیٹیوں سے نوازا۔ خیر سے اب پردادا ہیں۔
ان کے نزدیک زندگی مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے، جمود تو موت ہے۔ زندگی سے مطمئن ہیں۔ رب کے ممنون ہیں، جس نے انھیں صحت اور آگے بڑھنے کا حوصلہ ادا کیا۔
مرزا جمیل کا ہم پر ایک احسان ہے۔۔۔
اردو زبان و ادب کی کئی قدآور شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں اِس محسن عظیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ قارئین کے لیے یہاں چند مشاہیر کے الفاظ نقل کیے جارہے ہیں:
’’اِس ایجاد نے اردو کی طباعتی دنیا میں انقلاب برپا کرکے نسلوں پر احسان کیا ہے۔‘‘ (احمد ندیم قاسمی)
’’مرزا جمیل کا ہم پر ایک احسان ہے، جو خط نوری نستعلیق انھوں نے وضع کیا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔‘‘ (فیض احمد فیض)
اردو زبان اور اس کی ترقی میں جو کئی نوری سال حائل تھے، نوری نستعلیق نے ان نوری سالوں کو عبور کرلیا۔ (پروین شاکر)
’’نوری نستعلیق نے حُسن کے ساتھ ہماری زبان کو ہمارے عہد، بلکہ مستقبل کی رفتار عطا کردی ہے۔‘‘ (ابوالخیر کشفی)
’’ہم سب کو احمد مرزا جمیل کا احسان مند ہونا چاہیے، انھوں نے قومی زبان کے فروغ کے لیے ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔‘‘ (ڈاکٹر جمیل جالبی)
قلم سے کمپیوٹر تک یہ سفر (نوری نستعلیق) حیران کن بھی ہے، اور اور دل چسپ بھی۔ اور بیسیویں صدی کی ایجادوں میں ایک معجزہ بھی۔ (محسن احسان)
ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا!
احمد مرزا جمیل کو بے شمار اعزازات سے نوازا گیا۔
82ء میں تمغۂ امتیاز ان کے حصے میں آیا۔ اگلے ہی برس پشاور یونیورسٹی نے سپاس خیبر پیش کیا۔ 99ء میں انھیں جامعہ کراچی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا ہوئی۔ نجی کمپنیاں وقتاً فوقتاً ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈز سے نوازتی رہیں۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کو وہ اپنے لیے بڑا اعزاز قرار دیتے ہیں، جس کا، اُن کے نزدیک کسی ایوارڈ سے موازنہ ممکن نہیں۔ یوں تو پرنٹنگ کی دنیا میں بھی اُنھوں نے کئی کارنامے انجام دیے، مگر خواہش یہی ہے کہ اُنھیں نوری نستعلیق کے خالق کے طور پر یاد رکھا جائے۔
٭ حرکت میں برکت ہے
92 برس کی عمر میں بھی وہ انتہائی متحرک ہیں۔ کیا صحت کا راز ورزش میں پہناں ہے؟ اِس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں،’’نہیں باقاعدہ ورزش تو نہیں کرتا، مگر یہ ضرور ہے کہ حرکت میں برکت کا قائل ہوں۔ خود کو مصروف رکھتا ہوں، ذہن کو بھی استعمال کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حافظہ اچھا ہے۔‘‘
ان کے نزدیک آرٹسٹ کے ہاتھ میں چاہے برش ہو، قلم ہو، یا کمپیوٹر، اس کا ذہن اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ 80 برس کی عمر میں کمپیوٹر سے ان کی دوستی ہوئی تھی، جو ہنوز قائم ہے۔ روٹری انٹرنیشنل کے ڈسٹرکٹ گورنر اور ’’پاکستان ایسوسی ایشن آف پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹ‘‘ (PAPGAI) کے دو بار چیئرمین منتخب ہوچکے ہیں۔
![]()
کاروبار سے تو بیس برس قبل خود کو الگ کرلیا تھا۔ اب معمولات کچھ یوں ہیں کہ صبح اٹھ کر اخبار پڑھتے ہیں۔ ناشتے کے بعد باغیچے کی سیر کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں۔ مطالعہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ادبی مجلے توجہ کا مرکز ہیں۔ جو تحریر اچھی لگتی ہے، اُسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ظہرانے کے بعد قیلولہ نہیں کرتے۔ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں،’’میں اب بھی فیکٹری کے اوقات کار فالو کر رہا ہوں۔ قیلولے کی عادت نہیں پڑی۔‘‘
٭ تکمیل ایک نادر نسخۂ قرآن کی۔۔۔
ناممکن سے ممکن کا سفر
احمد مرزا جمیل کے کئی کارناموں میں ایک نمایاں کارنامہ اُن کے ادارے الیٹ پبلشرز کے تحت شایع ہونے والا قرآن پاک بھی ہے، جس کی تکمیل کی کہانی، ایک حیران کن کہانی ہے کہ اس کی خطاطی انوکھے انداز میں مکمل ہوئی۔
قصّہ کچھ یوں ہے کہ خطاطی ان کے والد، نور احمد کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسی شوق کے تحت الیٹ پبلشر کے قیام کے بعد اُنھوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ احمد مرزا جمیل قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کریں، جو فنی معیار سے انتہائی دیدہ زیب ہو۔ اِس منصوبے میں اہم ترین مرحلہ خطاطی کا تھا، جس کا بیڑا 72 برس کی عمر میں نور احمد صاحب نے خود ہی اٹھایا۔ چھے میں ماہ میں نو سپارے مکمل کیے تھے کہ بلاوا آگیا۔
والد کی اِس تمنا کے ناتمام رہنے کا خاندان کو شدید قلق تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھائی، ظہوراحمد نے خیال ظاہر کیا کہ نامکمل خطاطی سے عکس لے کر باقی سپارے ترتیب دیے جائیں۔ بہ ظاہر یہ طریقہ ناممکن تھا، تاہم دھیرے دھیرے یہ امکان کے قالب میں ڈھلنے لگا، جس کا تعاقب کرتے ہوئے خوش نویس، منشی رضا حسین اور ان کے چچا، مقبول احمد نے کام شروع کیا۔
طریقہ کچھ یوں تھا کہ کتابت شدہ 9 پاروں سے ایسے حروف، ترسیمے اور الفاظ منتخب کر کے چھاپ لیے گئے، جو نسخے کی گرافک خطاطی میں درکار تھے۔ پھر سطر کی گنجایش اور الفاظ کی نشست و کشید کی موزونیت سے تراشے منتخب کیے گئے۔ انھیں جوڑ کر ایک ایک سطر ترتیب دی گئی۔ حسب ضرورت اعراب اور نقطے لگائے گئے۔
یوں صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد، 14 برس کی محنت کے نتیجے میں یہ منفرد اور بے مثال نسخہ مکمل ہوا۔ تصحیح، تزئین اور طباعت میں مزید کچھ برس لگے۔ کمال یہ تھا کہ پہلے 9 اور باقی 21 پاروں میں زرہ برابر فرق نہیں تھا۔