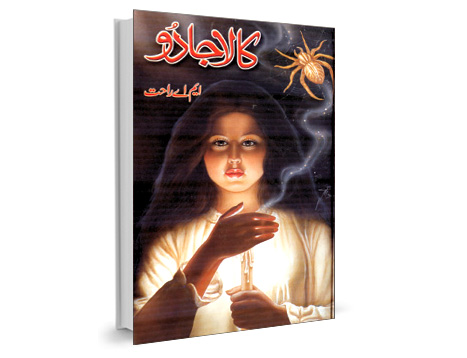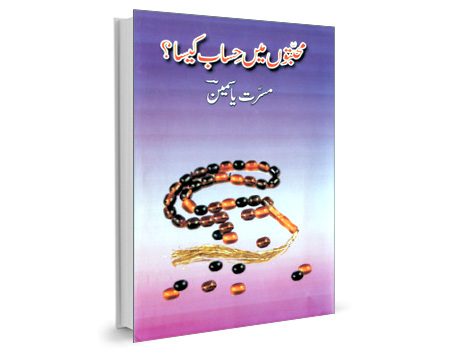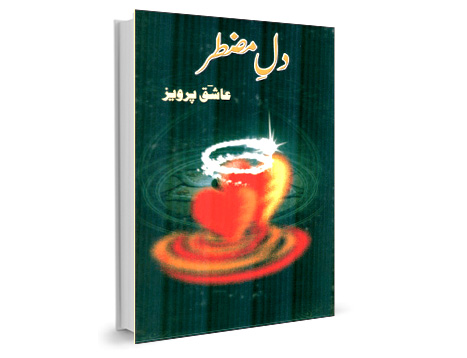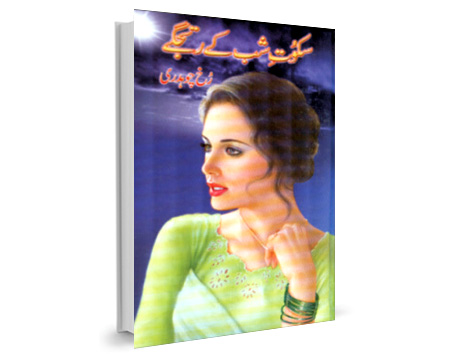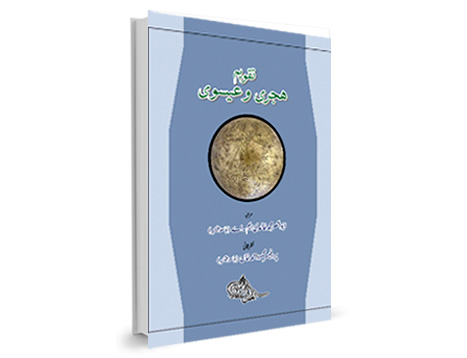چوہدری محمد سرور معروف بزنس مین اور سیاستدان ہیں۔ سالہا سال تک برطانیہ میں پارلیمنٹ کے ممبر رہے، انھوں نے ہر کڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔
دوہفتے قبل اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں کہ چوہدری محمد سرور کو حکومت نے پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ چوہدری محمد سرور بھی غیر متوقع طور پر اپنا طویل سیاسی کیرئیر چھوڑ کر پاکستان آگئے جس سے یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا کہ انھیں پنجاب کا گورنر بنایا جا رہا ہے۔ آج کل وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ ایکسپریس نے برطانیہ میں ان کے طویل سیاسی کیریئر اور پاکستان آنے کے حالیہ فیصلے کے تناظر میں ان کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا جس کی تفصیل نذر قارئین ہے۔
![]()
ایکسپریس: اپنے خاندانی پس منظر اور ابتدائی زندگی کے متعلق بتائیں۔
چوہدری محمد سرور: ہمارا خاندان 1947ء میں جالندھر سے ہجرت کرکے پاکستان آیا۔ فیصل آباد کے قریب چک109ہے ، ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں پر میرے انکل غلام محمد 47ء سے سال چھ مہینے پہلے واپس آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کسی نئی جگہ جائیں تو پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کچھ پیسے جمع کر کے پہلے اپنا گھر بنا لیں‘ آج بھی یہی سوچ ہے‘ تو میں حیران ہوتا ہوںکہ آج سے 50 سال پہلے بھی یہی سوچ تھی کہ کچے مکان ہی بنا لیں اور پھر انہیں پکا کرلیں گے اور وہی انہوں نے کیا۔ ہمارے پاس جو کاغذات تھے ان پر کلیم کے ذریعے 20 ایکڑ زمین حاصل کی جو کاغذات نہیں ملے اور ساتھ نہیں لا سکے ان کا کلیم نہیں ملا۔ 6، 6 ایکڑ زمین سب کے حصے میں آئی۔ پیدا میں ادھر ہی ہوا۔ پھر 5 سال کا تھا جب 331 گ ب چلے گئے۔
ہمارے رشتے دار بیٹھے تھے 331 گ ب پیر محل، تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ادھر چک 109 میں تو ہم اکیلے تھے۔کیونکہ برادری ادھر بیٹھی ہوئی تھی اس لئے ہم بھی بعد میں ادھر چلے گئے۔ میرے تایا جی کے کچھ پیسے جو ہندوستان میں بینک میں پڑے تھے‘ انہیں مل گئے۔ ان پیسوں سے انہوں نے کچھ زمین خریدی۔ میرے تایا جی نے زیادہ رقبہ لے لیا لیکن چھ ایکڑ مزید میرے والد صاحب کے نام کرا دیا۔ پرائمری تعلیم 331 گ ب میں حاصل کی‘ درختوں کے نیچے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ جو ناکافی سہولیات اب ہیں، مثلاً سکولوں کی چار دیواری نہیں ہے‘ پنکھے نہیں ہیں، یہ سب اس وقت بھی تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے دور کے استاد بہت Commited تھے اپنے کام سے۔ حالانکہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے جتنا آج کل ہوتے ہیں‘ لیکن اس وقت کے ٹیچر نے 12 جماعتیں بھی اگر پڑھی تھیں‘ تو اس کا خیال ہوتا تھا کہ جتنا علم اس کے پاس ہے‘ وہ اتنا ہی بچوں کو بھی دے دے۔ شام کو ماسٹر اپنے گھر میں بھی بلا لیتا تھا۔ اب تو کوئی ٹیچر ٹائم پر سکول جاتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ میرے گھر پر آ کے ٹیوشن پڑھ لو۔
بہر حال میں نے پرائمری ادھر سے پاس کی اور گھر سے دو میل دور 331گ ب میں ہائی سکول تھا‘ میں نے چھٹی جماعت میں وہاں داخلہ لے لیا۔ روز پیدل آتا جاتا تھا۔ والد صاحب 1957ء میں تایا کے ساتھ UK چلے گئے تھے۔ والدہ نے مجھے کہا کہ جب مڈل پاس کر لو گئے تو تمہیں سائیکل لے دوں گی اور دوسری بات یہ کہ اب نویں جماعت سے ڈیسکوں پر جا کے بیٹھنا‘ اب ٹاٹوں پر نہیں بیٹھنا۔ نویں جماعت میں مجھے سائیکل مل گیا۔ میں بہ مشکل پانچ چھ دن ہی سائیکل پر گیا ہوں گا کہ میں بور ہونے لگا۔ پہلے لڑکوں کے ساتھ جاتا تھا اور ہم گپیں مارتے جاتے تھے اور واپس آتے تھے‘ اس لئے کچھ دنوں بعد ہی اکتا کر دوبارہ پیدل آنے جانے لگا دوستوں کے ساتھ۔ 69ء میں میڑک کے بعد مزید تعلیم کے لئے فیصل آباد چلا گیا۔ فیصل آباد سے میں نے گریجویشن کی ہے اور پھر 76ء میں یوکے چلا گیا۔
ایکسپریس: برطانیہ میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کی جانے والی جدوجہد تفصیل سے بتائیں؟
چوہدری محمد سرور: اس وقت خیال یہ تھا کہ جب ادھر جائیں گے تو درختوں پر پیسے لگے ہوں گے‘ VIP لائف ہو گئی‘ وہاں سے بہت سارے پیسے لے آئیںگے اور پھر یہاں آ کر اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ میرے والد صاحب اور بھائی بھی پہلے یوکے چلے گئے تھے۔ میں نے بھائی اور کزن کی دکان پر ان کے ساتھ کام شروع کر دیا‘ لیکن وہ دکان افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ میری‘ میرے بھائی اور کزن کی تنخواہ دے سکے۔ اس لئے میں نے سیلز مینی شروع کر دی۔ جس طرح ادھر جمعہ یا اتوار سستے بازار لگتے ہیں‘ اسی طرح ادھر بھی ہفتے میں دو تین دن سستے بازار لگتے ہیں۔ میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ میں نے چھ مہینے اس طرح مارکیٹ میں سیلز مینی کی۔
میں کبھی سوچوں کہ سب کچھ چھوڑ کے دو جماعتیں اور پڑھ لوں یا کسی بینک وغیرہ میں ملازمت کر لوں۔ ایک پروفیسر صاحب تھے قریشی صاحب‘ فیصل آبادایگری کلچر یونیورسٹی کے‘ ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا۔ وہ ادھر آئے تو میں انہیں کھانے کے لئے لے گیا اور بتایا کہ بڑا پریشان ہوں۔ خاص طور پر وہاں بڑی ٹھنڈ تھی‘ کئی دن سورج نہیں نکلتا تھا۔ گلاسکو ‘ سکاٹ لینڈ جہاں ہم رہتے ہیں‘ ادھر لندن سے بھی زیادہ شدید سردی پڑتی ہے۔ پروفیسر صاحب سے مشورہ مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے کزن کب یہاں آئے تھے؟ میں نے کہا کہ مجھ سے 10,8 سال پہلے آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی تم ان سے 10 سال پیچھے ہو اور اگر دوبارہ پڑھنے لگ گئے تو 20 سال پیچھے ہو جاؤ گئے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈگریاں میرے پاس ہیں۔ لیکن 22 تاریخ ہوتی ہے تو دال پر گزارہ کر رہا ہوتا ہوں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوںکہ بزنس جس پر تم لگے ہو۔ اس کو نہ چھوڑو بلکہ سب کچھ بھول بھال کے اس پر ڈٹ جاؤ۔ اب تمہیں 30 پاؤنڈ یہاں سے مل رہے ہیں ہفتے کے۔ ہو سکتا ہے کہ نوکری میں 50 پاؤنڈ ملنا شروع ہو جائیں‘ لیکن پھر تم ساری عمر نوکری ہی کرو گے۔ اس لئے بزنس پر ڈٹ جاؤ۔ چنانچہ یہ بات میں نے پلے باندھ لی۔
میرے کزن اور بھائی کی جو دکان تھی وہ نفع نہیں دے رہی تھی اور پارٹنرز کے درمیان غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی۔ ایک دن میرے انکل، جو میرے سسر تھے، جہاں میں کام کرتا تھا‘ وہاں آئے تو مجھے دیکھا کہ ٹھنڈ میں کھڑا کپڑے بیچ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچا تو کہنے لگے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں اور کپڑوں کی دکان بنا کے دیتا ہوں‘ تم وہ کر لو‘ کیونکہ سخت کام تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے صبح تک کا ٹائم دیں‘ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ رشتہ بڑا نازک ہے‘ پہلے ہی کام نہیں ہو رہا‘ اگر میں ان سے 10,7,5 ہزار پاؤنڈ قرض لے کے کام شروع کرتا ہوں اور وہ کامیاب نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا ہے تو ساری عمر بیوی کی لعن طعن برداشت کرنا پڑے گی۔ اس لئے یہی کام بہتر ہے۔ میں صبح ان کے پاس گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ناتجربہ کار ہوں اور مجھ سے کام نہیں ہو رہا تو میں تھوڑے سے دھکے اور کھا لوں‘ پھر آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی توبتاؤں گا۔ پھر بھائی کی جو دکان تھی میں نے وہ لے لی۔ دکان ویسے بھی خسارے میں جا رہی تھی‘ میں نے سامان‘ شیلفوں کے پیسے دے دیئے۔ کچھ بینک سے قرض لے لیا اور کچھ ہزار پاؤنڈ میرے اپنے پاس جمع تھے۔ اس طرح سے میں نے وہ دکان خریدی۔
![]()
ادھر مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ وہ ایریا ڈویلپمنٹ سکیم میں آتا تھا‘ اردگرد کے گھر خالی پڑے ہوئے تھے‘ اس لئے اس علاقے میں چوہے بہت آئے ہوئے تھے۔ وہ کونے کھدروں سے چھپ کر آتے‘ بسکٹ بھی کتر جاتے تھے اور چاکلیٹ بھی۔ دن کے وقت یہ ساری چیزیں ضائع کرنا پڑتی تھیں۔ اتنے خطرناک چوہے تھے کہ پلاسٹک کی جو بوتلیں ہیں‘ ان کو بھی کتر کر چلے جاتے تھے۔ میں نے پھر دو بلے لا کر اس دکان میں چھوڑ دیئے۔ آپ یقین کریں کہ وہ چوہے اتنے خطرناک تھے کہ انہوں نے ان بلوں کو بھی مار دیا۔ جب میں نے صبح دکان کھولی تو دیکھا کہ دونوں بلے مرے پڑے تھے۔ پریشان کھڑا حل سوچ رہا تھا کہ ایک بوڑھا گورا آیا اور کہنے لگا:
Hellow son! How are you?
میں نے جواب دیا:Very Bad
کہنے لگا: Whats the Problem
میں نے کہا :Problem are rats, they are eating my all profit and I have no solution
گورا کہنے لگا: Son! I have a solution
میں نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی! تمہارے پاس کیا حل ہے۔ دکان بند کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں تم ایک دن چھ بجے دکان بند کر کے مجھے یہاں لاک کر جانا‘ اس کے علاوہ اینٹیں لے آؤ اور سیمنٹ لے آؤ۔ آئیڈیا اس کا بڑا زبردست تھا۔ اس نے کہا کہ دیواروں سے‘ جہاں سے چوہے آتے ہیں‘ ان پر سیمنٹ اور اینٹوں سے دو دو انچ کی ایک اور تہہ چڑھا کر انہیں بند کر دیتے ہیں پھر چوہے اندر نہیں آ ئیں گے۔ خیر اس بوڑھے گورے نے ایک رات ایک دیوار کر دی‘ دوسری رات دوسری اور پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی دیوار کوبھی اینٹوں اور سیمنٹ سے مکمل بند کر دیا۔ اب چوہوں کا آنا بند ہو گیا اور دکان نفع دینے لگی ۔
میری زندگی کبھی ہموار نہیں رہی‘ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تکلیف رہی ہے۔ جب میں سوچتا ہوںکہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے‘ وہاں بھی تکلیف آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تنازع کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا۔ برطانیہ میں بھی مجھے Britains most controversial MP کہا جاتا تھا۔ اب بھی جب سال چھ مہینے ہو جائیں اور لگے کہ زندگی ہموار ہو گئی ہے تو مجھے زندگی میں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے اور میں مشکل ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہلا گلا ہوتا رہے تو بہتر ہے۔
بہرحال میں ایک دن دکان پر گیا تو نوٹس آیا ہوا تھا ، دکان کو منہدم کرنے کے آرڈر تھے کہ اتنے دنوں میں خالی کر دو۔ میں نے نوٹس دینے والوں کو فون کیا کہ آپ سے ایک ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کل آنے کا کہہ دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، ایک بنا بنایا کام ہے۔ آپ اس طرح سے نہیں کرسکتے کہ میری دکان کو ختم کردیں۔ آپ مجھے اس کے بدلے کوئی اور دکان دے دیں۔ وہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے مجھے لسٹ دے دی کہ یہ شہر میں خالی دکانوں کی فہرست ہے، تم اس میں اپنی پسند کی دو، تین دکانیں پسند کرکے مجھے بتادو۔ ایک دکان مجھے پسند آئی وہ کہنے لگے کہ آفر بھیج کے وہ دکان لے لو۔ میں نے کہا تم بتائو کہ تم نے کتنے پیسے لینے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم بتاتے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ چلو آئیڈیا ہی دے دو کہ کتنے پیسوں کی آفر بھیجوں۔
اس نے مجھے بتایا، میں نے آفر بھیج دی اور وہ دکان مجھے مل گئی۔ میں نے اپنا سامان اس دکان میں منتقل کردیا۔ یہ دکان بہت بہتر تھی، سیل بہترہوگئی، پھر اس کے بعد ڈسٹری بیوشن، ہول سیل کا کام شروع کردیا۔ Always you learn, you Pick the ideas مثلاً ہم کیش اینڈ کیری میں جاتے تھے سامان خریدنے۔ ہم سوچتے تھے کہ ہم سارا دن کماتے ہیں اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور سارے ان کودے دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم کیوں نہ کریں یہ کام۔ میں نے دو چیزیں نوٹ کیں کہ گاہک ہم سب کالے ہوتے تھے، لیکن کیش اینڈ کیری کے مالک سارے گورے تھے۔ اور سلوک بھی ان کا کوئی اچھا نہیں تھا، میں سوچنے لگا کہ اگر میں خود بنائوں اور مال بھی انہیں اچھادوں اور سلوک بھی اچھا کروں تو یہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں آئیں گے۔ پھر میں نے ہول سیل کا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ کاروبار ترقی کرتا گیا۔
ایکسپریس: اب اپنے سیاسی کیرئیرکے بارے میں بتائیں؟
چوہدری محمد سرور: 1982ء میں لیبر پارٹی جوائن کی ۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تو ہم نے برطانیہ میں Save the Bhutto کمپین چلادی۔ ریلیوں میں جانا، کونسلروں سے رابطے کرنا، جن سے زیادہ رابطے ہوئے ان کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا۔ اس طرح ان سے ایک تعلق بن گیا۔ پھر سوچا کہ یہ بھی غریبوں کی بات کرتی ہے، انصاف اور برابر حقوق کی بات کرتی ہے، جو میرے آئیڈیلز ہیں، اس کے بھی ہیں، اس لیے میں لیبر پارٹی میں شامل ہو گیا۔ دوستوں نے کہا کہ الیکشن لڑلو، میں نے کہا ٹھیک ہے اور الیکشن کے لیے کھڑا ہوگیا۔ حالانکہ 28 سال سے یہ ٹونی کی سیٹ تھی، کیونکہ وہاں سارے امیر لوگ رہتے تھے، بڑے گھروں میں رہتے تھے، وہ سب ٹونی کو ووٹ دیتے تھے۔ 92ء میں پہلی دفعہ میں کونسلر منتخب ہوا اور 95ء میں دوسری دفعہ۔ پہلی دفعہ میں 400 ووٹ سے جیتا تھا اور دوسری دفعہ ایک ہزار ووٹ سے۔
پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ MP کے لیے بھی لڑا جائے۔ میرا جو MP تھا، اس نے ریٹائر ہونا تھا۔ میں نے اس سے ملاقات کی، اس نے مجھے کہا کہ تم میری جگہ لینے کے لیے موزوں شخص ہو۔ میں نے کہا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس نے ہامی بھر لی۔ جب تک تو میں کونسلر تھا، اس وقت تک کوئی میرے خلاف نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے: Muhammad is great ، Muhammad is doing good job ، Muhammad cares people وغیرہ۔ لیکن جس دن اخباروں میں آیا کہ Muhammad would be first Muslim MP in Britain ، Muhammad would be first Asian MP in Scotland تو پتا نہیں دشمن کہاں سے آئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ گویا آسمان ٹوٹ پڑا اور زندگی مشکل ہوگئی۔ اچانک سارے عہدے دار، سیاسی لوگ اور میڈیا میرے خلاف ہو گیا۔
جب میری مخالفت بڑھتی ہے تو میں اور زیادہ متحرک ہوجاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ لو اب یہ لڑائی لڑنی ہے، اللہ مالک ہے۔ 95ء میں سلیکشن کے لیے گیا اور انہوں نے دھاندلی سے مجھے ایک ووٹ سے ہرا دیا۔ برطانیہ، یورپ بلکہ امریکہ میں بھی کوئی مسلم MP نہیں تھا اور یہ دنیا کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ پھر خاص کر وہ بندہ جس نے 1986ء میں وہاں فلسطین پر کانفرنس کرائی۔ جس نے فلسطین کا جھنڈا سٹی چیمبرز (سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ) پر لہرا دیا اور تین دن تک یہ جھنڈا لہراتا رہا۔ انہوں نے میرے 52 ووٹ مسترد کردیئے تھے۔ 345 ووٹ میرے تھے اور 345 ووٹ میرے مخالف کے۔ لیکن پہلے بیلٹ میں اس کا ایک ووٹ زیادہ تھا۔ انہوں نے ووٹ اس بنیاد پر مسترد کیے تھے کہ دستخط آپس میں نہیں ملتے۔ مثلاً جب آپ ووٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو، اسں وقت دستخط کرتے ہو اور جب اپنا ووٹ بھیجتے ہو، اس وقت بھی دستخط کرتے ہو۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دستخط ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنی پارٹی سے کہا کہ 52 ووٹ آپ نے اس بنیاد پر مسترد کیے ہیں کہ دستخط آپس میں نہیں مل رہے۔ یہ دستخط آپ ہینڈ رائٹنگ کے کسی ماہر کو بھجوادیں۔ وہ اگر کہہ دے کہ یہ واقعی نہیں ملتے تو میں شکست تسلیم کرلوں گا۔اس لیے آپ اسے چیک کرالیں یا پھر ری بیلٹ کرا لیں لیکن پارٹی کے جنرل سیکرٹری نے ماننے سے انکار کر دیا اور میرے حریف امیدوار مائیک واٹسن کے منتخب ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔
![]()
رزلٹ کے بعد پریس کانفرنس میں پارٹی نے اعلان کیا کہ ہمارا یہ امیدوار منتخب ہوگیا ہے۔ اس کے بعد مائیک واٹسن کی باری آئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگرچہ فتح کا مارجن بہت کم ہے، لیکن Victory is Victory چاہے ایک ووٹ سے ہی کبوں نہ ہو۔ پھر میری باری تھی، میں نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور اپنی شرائط پیش کیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ پارٹی سے میرا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ وہ الیکشن null and void قرار دے۔ ورنہ مجھے انصاف کے لیے عدالتوں کا ہی رخ کرنا پڑے گا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگلے دن کی اخباروں میں یہ سب آگیا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کرادیتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کسی بھی آزاد برطانوی ادارے سے تحقیق کرا لیں، مجھے اس کے نتائج قبول ہوں گے۔ انہوں نے ایک unity Balleting Services کے نام سے ادارہ تھا، اس کو تحقیقات کے لیے کہہ دیا۔ اس کی رپورٹ بڑی تباہ کن تھی، جس میں کہا گیا کہ انتخاب میںدھاندلی ہوئی ہے اور جو ووٹ مسترد کیے گئے ہیں، ان کے دستخط آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ پارٹی نے الیکشن null and void قرار دے دیئے۔
اب پارٹی نے کہا کہ تینوں امیدواروں کی جگہ نئے امیدوار لے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مائیک واٹسن سے میری کوئی ذاتی لڑائی تونہیں ہے جو میرے ساتھ اسے بھی رد کررہے ہو۔ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر جمہوریت کہاں گئی۔ خیر انہی امیدواروں کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہوا اور میں 82 ووٹ سے جیت گیا۔1997ء میںMP کا الیکشن ہوا۔ اللہ کی مہربانی سے میں جیت گیا اور برطانیہ کے پہلے مسلمان MP بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ جو کہ بہت بڑی بات تھی۔ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ قائداعظم نے بھی برطانوی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہوکر یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش وہ کسی دن اس کے ممبر بینں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائداعظمؒ کا خواب میں نے پورا کردیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پر میں نے حلف لیا۔ پھر دوسرا الیکشن ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے خلاف جو کیسز بنے، جج نے تمام کیسز Dismissed کردیئے۔ لاکھوں روپے دے کر جتنے گواہ میرے خلاف کھڑے کیے گئے سب کو ہم نے غلط ثابت کردیا۔ جیسے ہی میں MP بنا، فوراً ہی حملہ شروع ہوگیا۔ میرا سیاسی کریئر ختم کرنے کیلئے ایک ملین پائونڈ فنڈ انہیں میسر تھے، میری کتاب آ رہی ہے جس میں لوگ تفصیل سے پڑھیں گے یہ سب۔ جب میں عدالت میں کیس جیتا تو کچھ تو میڈیا ٹھیک ہوگیا، لیکن جو بگڑا ہوا تھا اس نے لکھا کہ محمد سرور قانون کی عدالت میں تو جیت گیا ہے لیکن عوام کی عدالت میں ہار جائے گا۔ جب عوام کی عدالت کی باری آئی تو پہلے الیکشن میں میری 3000 کی اکثریت تھی اور اگلے الیکشن میں عوام مجھے ساڑھے چھ ہزار کی برتری پر لے گئی۔ یعنی دگنی سے بھی زیادہ۔ پھر میڈیا نے ہاتھ کھڑے کردیئے۔
ایکسپریس: آج کل میڈیا میں مختلف حوالوں سے آپ پر تنقید بھی ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
چوہدری محمد سرور: ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ سیاست اور جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوسکتی ہے اور اسی کی خامیاں دور ہوسکتی ہیں، جب میڈیا ان کی خامیوں کو اجاگر کرے۔ سیاستدانوں کو بھی اسے صحیح طور پر لینا چاہئے کہ جو انہیں ان کی خامیوں کا بتائے وہ ان کا مخالف نہیں بلکہ دوست ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں کچھ غلط کررہا ہوں تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے بتائیں کہ میں کہاں غلط ہوں۔ تو یہ اچھی Contribution ہے میڈیا کی، جو وہ کررہا ہے۔ لیکن اسی طرح میڈیا کو بھی اخلاقیات اور انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جسے بھی طاقت اور اختیار ملا اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔
فوج کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے غلط استعمال کیا۔ سیاستدانوں کے پاس آئی تو انہوں نے غلط استعمال کیا۔ اسی طرح میڈیا نے بھی کیا۔ طاقت کا غلط استعمال ہمارے مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ولایت میں کسی بندے پر الزام لگتا ہے تو وہ مستعفی ہو جاتا ہے۔ اب الزام تو کل میں کسی پر بھی لگادوں تو کیا وہ مستعفی ہو جائے گا؟ وہاں مستعفی وہ ہوتا ہے جو beyond reasonable doubt مجرم ہو، یعنی وہ بندہ جو عدالتوں کا سامنا نہیں کرسکتا۔ ادھر قانون کی اور عدالتوں کی بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی یہ نہیں کرسکتا کہ کسی کی سفارش کراکے اپنے آپ کو بچالے۔
کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جس وقت میں MP تھا، اس وقت استعفی دے کر پاکستان کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں یقین رکھتا تھا کہ میں برطانوی اقلیتی مسلمانوں، بلکہ پاکستان اور یورپی دنیا کے مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر کام اس حیثیت میں کرسکتا ہوں۔ اب جب میں ریٹائر ہوچکا ہوں اوروہ خلاء نہ صرف میرے بیٹے بلکہ دوسرے ممبران پارلیمنٹ کی صورت میں پر چکا ہے۔ میرا بیٹا نہ صرف ممبر پارلیمنٹ ہے بلکہ وہ پارٹی کا ڈپٹی لیڈر بھی ہے۔ تو وہ لوگ پاکستان اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ اوردفاع کررہے ہیں۔
ایکسپریس: کیا میاں برادران سے ذاتی تعلق کی وجہ سے آپ کا نام اہم سیاسی عہدے کے لیے زیر غور ہے؟
چوہدری محمد سرور: بات تعلقات کی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ میں اس ملک کیلئے کیا کرسکتا ہوں۔ باہمی تعلق کا تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اگر میں اس ملک کیلئے Contribute کرسکتا ہوں تو پھر بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں 35 سال ملک سے باہر رہا ہوں، لیکن کوئی ایک ایسا موقع بتادیں جب یہاں کے لوگوں کو میری ضرورت ہو اور میں نہ آتا ہوں۔ ادھر سے ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں میری کتنی مصروفیات ہوں گی۔ جب زلزلہ آیا تو میں فوراً پہنچا اور کئی دن لگائے۔ متاثرہ علاقوں میں گھر، سکول، ہسپتال وغیرہ بنائے پھر جو حکومت سے گرانٹ لی وہ علیحدہ ،میں نے حکومت سے کہا وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے فوری طور پر چینک ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے۔ وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے چینک ہیلی کاپٹروں نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ کسے نہیں پتا۔ ہڈیوں کا مسئلہ ہوا تو میں خود وہاں سے Artifical limbs ساتھ لے کر آیا، برٹش ڈاکٹر یہاں پہنچے۔
انہیں چھٹیاں لے کر دیں کہ وہ تنخواہ کے ساتھ یہاں متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے کام کریں۔ گلاسکو سٹی کونسل کا ایک ایمپلائی تھا، اسے چھ مہینے کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی لے کر دی تاکہ وہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں فل ٹائم کام کرے۔ سیلاب آیا تو میں دو مہینے ادھر تھا، سندھ، خیبر پختونخوا، کوٹ ادو میں کام کیا۔ سکول، گھر تعمیر کرائے۔ جنوبی پنجاب میں 10 ہزار فوڈ پارسل لوگوں میں تقسیم کیے، آرمی والے کہتے کہ یہ بہترین فورڈ پارسل تھے جو لوگوں میں تقسیم ہوئے۔ سو میرا جذبہ اور محبت جو اس ملک کے لیے ہے وہ میرا نہیں خیال کہ Questionable ہے۔ اس کے علاوہ MP ہونے کے باوجود میں نے رجانہ میں ہسپتال بنایا۔ 60 ہزار مریض سالانہ وہاں علاج کی سہولیات لے رہے ہیں۔ پھر چیچہ وطنی ہسپتال بنایا۔ ادھر 70 ہزار مریضوں کا سالانہ علاج ہورہا ہے۔ پیرمحل میں فائونڈیشن پبلک سکول بنایا ہے جہاں 350 بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جب میں یہاں نہیں بھی تھا اس ملک کے لیے کام کررہا تھا اور اب بھی انشاء اللہ جو ہو سکا کرتا رہوں گا۔
ایکسپریس: کہا جارہا ہے کہ میاں برادران کی کسی خدمت کے پیش نظر آپ کو یہ عہدہ دیا جارہا ہے؟
چوہدری محمد سرور: بات یہ ہے کہ نہ میاں برادران کی میں نے کوئی خدمت کی ہے، نہ کوئی فیور کی ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام ہے اور Merit پر ہوتا ہے تو ہونا چاہئے۔ میاں برادران ہوں، کوئی اور ہو، میں ہوں، اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہورہی ہے اور قانون اس کی ہیلپ کرتا ہے تو یہ ان کی فیور نہیں ہے، یہ اس کا right ہے۔ یقین مانیں کہ میں قطعاً ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ میں نے میاں برادران کو کوئی فیور دی ہے۔ یا میاں برادران سے میرا جو رشتہ ہے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق لیفٹ سے ہے۔ آپ لیبر پارٹی کے ہیں، وہ رائٹ کے۔ میں جتنی دفعہ بھی میاں شہباز شریف صاحب سے ملا ہوں لاہور میں اور یوکے میں میاں نواز شریف صاحب سے ملا ہوں یہاں پہ کبھی ہماری یہ گپ شپ نہیں ہوتی کہ آج موسم اچھا ہے، ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کے لئے کیا کرسکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میری ان سے گفتگو ہوتی ہے‘ نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے جو بات نوٹ کی ہے کہ ان میں غریبوں کے لئے اور اس ملک کے لئے کچھ کرنے کا جذبہ ہے۔
![]()
سوشلسٹوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ ان کا جذبہ کتنا ہے‘ لیکن میں 100 فیصد آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی نیت صاف ہے۔ وہ ملک کو دوبارہ ٹریک پر لانا چاہتے ہیں اور میں اسی وجہ سے اپنی ساری توانائی اور تجربہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔اگر میں یقین رکھتا کہ وہ ایماندار نہیں ہیں اور کام کرنا نہیں چاہتے تو میں کبھی ان کے ساتھ شامل نہ ہوتا۔ بہت سے لوگ‘ جو میرے خلاف لکھ رہے ہیں‘ مجھے کہتے تھے کہ میرا جو مقام ہے‘ وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کسی ایک جماعت کو سپورٹ کروں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کی بقا اور بہتری کے سامنے میرا مقام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 1122 کے عہدے داروں کی انگلستان میں ٹریننگ میں نے ممکن بنائی ہے۔ ایک ادارہ ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہی میری نجات کا ذریعہ بنا دیں۔اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ میں امپورٹڈ ہوں۔امپورٹڈ تو فصلی بیٹرہ ہوتا ہے جو آیا اور بھاگ گیا۔ میں تو 35 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں۔
میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوںکہ اگر لوگوں کو پرکھنا ہے تو ان کی باتوں سے نہ پرکھو۔ ان کا ٹریک ریکارڈدیکھ لو بس۔ورنہ میں سوچ سکتا ہوں کہ اب ریٹائر ہو گیا ہوں تو سکون سے رہوں یا بزنس وغیرہ ٹھیک ہے تو مجھے ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر یہ تو ابھی ذمہ داری کی بات ہے۔ لیکن اگر عہدہ نہ بھی ہوتا تو میں نہ آتا ادھر؟ تین سال ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے مجھے۔ میں ہر سال ادھر آتا ہوں اور آدھا ٹائم ادھر رہتا ہوں‘ آدھا یو کے میں۔ ادھر میں اپنے ادارے چلاتا ہوں۔ کچھ دوست ناراض ہیں کہ ملاقات نہیں ہوسکی‘ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت مغرور ہو گیا ہوں‘ بلکہ ایک دن میرا فاونڈیشن ہسپتال میں گزر جاتا ہے‘ ایک دن رجانہ میں‘ ایک دن پیر محل میںگزر جاتا ہے۔ میں کوٹ ادو میں مشہور ہو گیا لوگوں میں‘ پھر چارسدہ میں جانا ہوتا ہے تو میں یہاں رفاہی کاموں میں ہی مصروف ہوں، کون سا اپنے ذاتی کام کر رہا ہوں۔
ایکسپریس: ملک کو بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے اور آپ اس ملک کے لئے خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں۔ گورنر کا ایک آئینی عہدہ ہے جس کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے‘ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو کوئی اور موزوں عہدہ دیا جاتا‘ جس سے آپ ملک کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوتے؟
چوہدری محمد سرور: دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو باہر کے لوگوں کے مسائل ہیں‘ ان حالات میں بھی وہ تمام تر مشکلات کے باوجود 15بلین ڈالر زرمبادلہ ادھر بھیجتے ہیں۔ ہر تیسرا پاکستانی وہاں ان مسائل کا شکار ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ ہوا ہے‘ کسی پر جعلی کیس بنا دیا گیا ہے‘ کوئی اغواء ہو گیا ہے‘ اگر میرے ادھر آنے سے لوگ تحفظ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پیسہ بھیجتے ہیں تو کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا‘ تو وہ زیادہ سرمایہ کاری کریں گے۔ اسی طرح NGO,s بھی۔ میں ایک سوشل ورکر ہوں‘ جو ہیلتھ‘ ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کس جگہ پر میں بیٹھ کے اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ باقی اگر نہ بھی ملی گورنری‘ تو بھی لوگوں کی خدمت ہم نے کرنی ہے۔ پھر ہم نے کون سا پیچھے ہٹ جانا ہے۔ جب سال چھ مہینے گزر جائیں گے آپ دیکھنا کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔
ایکسپریس: جب آپ گورنر بنیں گے تو گورنمنٹ چارٹر یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ساتھ ہی بن جائیں گے۔ یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے کہ کبھی تو VC کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ 5/5 سال سیٹ خالی رہتی ہے‘ لیکن وہ ٹیچرز بھرتی نہیں کر سکتا اور کبھی اتنی ڈھیل دے دی جاتی ہے کہ وہ آرام سے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کر لیتے ہیں؟
چوہدری محمد سرور: بات یہ ہے کہ تقرری کے جتنے اختیارات ہیں وہ تو چیف منسٹر کے پاس ہیں اور ماضی کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ جن کا انہوں نے تقرر کیا ہے‘ میرٹ پر کیا ہے۔مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سیاسی جماعتوں کے اندر ہر وقت لڑائیاں چلتی رہتی ہیں مختلف شہروں‘ علاقوں میں، اسی طرح ادھر بھی یہ ہو رہا ہے۔ استاد ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بچوں پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ سو ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فیصلے تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کریں گے۔ لیکن ایک ٹیم کی حیثیت سے انشاء اللہ امید ہے کہ بہتری لائیں گے۔
ایکسپریس: آپ سکاٹ لینڈ انرجی کمیشن کے سربراہ بھی رہے ہیں‘ ہمارے ملک میں جو شدید بحران آیا ہوا ہے‘ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
چوہدری محمد سرور: میں 5 سال سکاٹش افیئر سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں۔ ادھر جتنی سلیکٹ کمیٹی ہیں‘ وہ طاقتور ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ مسئلہ کو سمھجنا‘ تحقیق کرنا‘ لوگوں سے ثبوت اکھٹے کرنا اور پھر اس کا حل تجویز کرنا۔اس طرح پاکستان میں بھی جو توانائی بحران ہے، اس کا کثیر الجہتی حل تلاش کرنا پڑے گا۔ مثلاً اس ملک میں جو دھوپ ہے‘ وہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جرمنی میں دھوپ بھی نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سولر سے بجلی پیدا کرنا فائدہ مند ہے۔ جتنی بھی سٹریٹ لائٹس ہیں‘ جتنے سکول ہیں‘ جہاں زیادہ بجلی کی ضرورت نہیںہے، صرف پنکھے ہی چلنے ہیں‘ وہاں آپ جتنی بھی سولر بجلی لے آؤ گے‘ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ پھر جو سب بڑا سبب میں سمجھتا ہوں وہ ہیں لائن لاسز۔ ایک مرحلہ ہے پیداوار کا، پھر ترسیل اور بجلی کی تقسیم۔ ایک تو ان تینوں کی آپس میں کوآرڈینیشن پوری نہیں۔ ان تینوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔
ایک تو لائن لاسز میں کہ بجلی پوری نہیں پہنچ رہی اور راستے میں ضائع ہو رہی ہے اور دوسرا بجلی چوری ہے۔ لائن لاسز ہمارے 22,25 فیصد ہیں۔ دنیا میںکہیں اور چلے جاؤ‘ کہیں چار فیصد ہوں گے کہیں تین فیصد۔ ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ریکوری ہے۔ اگر ریکوری ہی پوری نہ ہوتو کام کیسے چلے گا۔ آپ تیل سے بجلی پیدا کرتے ہو‘ تیل نہیں ہو گا تو ادارہ کیسے چلے گا‘ سو ان سب کو ٹھیک کرنا ہو گا۔ صلاحیت بڑھانی پڑے گی‘ پھر لوگوں میں سماجی شعور کے لیے آگاہی مہم چلانا ہو گی۔مثلاً ایئر کنڈیشن اگر 16/20 پر رکھو گے تو یہ زیادہ بجلی کھاتا ہے۔ 24 پر رکھو گے تو تمہاری صحت کے لئے بھی بہتر ہے اور اس سے خرچ بہت کم ہو جائے گا۔Efficiency saviny Bulb اگر آپ لگا دو گے تو 20 فیصد بجلی خرچ ہو گی اور 80 فیصد بجلی بچ جائے گی۔ ہمیں کم از کم سکولوں اور سرکاری ہسپتالوں میں یہ بلب لگا دینے چاہئیں۔ لیکن بڑے بڑے مسائل ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا‘ راتوں رات بہتری نہیں آئے گی۔ عوام کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ انشاء اللہ بحران سے نکل آئیں گے۔
اپنی غربت کو کبھی نہیں چھپایا
ہم ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں تھا جیسے کچھ لوگ غربت سے نکل کر امارت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں جیسے وہ اربوں پتی تھے اور کوئی بڑے خاندانی لوگ تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بندہ 5/6 ایکڑ کی زمین سے ترقی کر کے آگے چلا گیا ہے تو وہ شاید خاندانی نہیں رہتا۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات پر فخر کرتا ہوںکہ اتنی سادہ شروعات سے میں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ میں نے کبھی اپنی غربت کو نہیں چھپایا۔ میں جب کسی سکول یا یونیورسٹی میں لیکچر دینے جاؤں تو میں ہمیشہ تین باتیں ضرور کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ کبھی نہیں بھولنا کہ تم کیا تھے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ جس جگہ‘ علاقے سے تمہارا تعلق تھا‘ بعد میں تم دنیا کہ کسی بھی حصے میں چلے جاؤ‘ لیکن اپنے آبائی علاقے کے لیے ضرور کام کرو۔ تیسری بات جو میں کہتا ہوں کہ وقت کی پابندی کرو‘ وقت کو ضائع مت کرو بلکہ اس کا بہترین استعمال کرو۔ تفریح کے لئے بھی وقت ضرور نکالنا چاہئے‘ لیکن ایک توازن ضرور قائم رکھنا چاہئے کہ کتنا ٹائم پڑھنا ہے‘ کب کھیلنا ہے اور لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے‘ وغیرہ۔
ملٹی کلچرل سوسائٹی
انگلستان میں مختلف قومیتوں کے لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں‘ چاہے انڈیا سے ہوں‘ پاکستان سے ہوں‘ بنگلہ دیش وغیرہ۔ خود میرے حلقے میں 60 قومیتوں کے لوگ بستے ہیں۔ ہم ادھر کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے‘ وہ بھی ہم سے بہت سی باتیں سیکھتے ہیں۔ ہم اس سوسائٹی کو rich سوسائٹی اس لئے کہتے ہیںکہ وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے۔ مثلاً جب ہم لوگ وہاں گئے ہیں تو انگریز صبح 9 بجے دکان کھولتا تھا اور 5 بجے بند کر دیتا تھا۔ اور ہفتے کے دن دو بجے بند کر دیتا تھا۔ ہم جب پاکستانی، انڈین وہاں گئے تو ہفتے میں 7 دن ہی دکانیں کھولنے لگ گئے اور پھر لیٹ بھی کھولنے لگے۔ اب انگریز بھی 24 گھنٹے دکان کھولنے لگ گیا ہے۔ ادھر کا جو ہیلتھ نظام ہے‘ اگر ایک دن ہم ایشین ہڑتال پر چلے جائیں تو وہ معطل ہو کر رہ جائے۔ ہر جگہ ایشین ڈاکٹر‘ پاکستانی ڈاکٹر‘ مجھے جب وہاں ہارٹ پرابلم ہوا تو میں مانچسٹر کے ہسپتال میں داخل ہوا۔ ادھر یورالوجی کا ڈاکٹر بھی پاکستانی‘ کارڈیالوجی کا ڈاکٹر بھی پاکستانی‘ کڈنی کا جو سپیشلسٹ ہے وہ بھی پاکستانی‘ تو میں کہنے لگا کہ بھائی! مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں لاہور میں بیٹھا ہوں۔
ملکی سیاسی جماعتوں کی بیرون ملک شاخیں
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں مارشل لاء ہے پھر تو وہاں ہمیں اکھٹے ہو کر جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنی چاہئے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جمہوریت جتنی بھی بری ہو، وہ آمریت سے بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ لیکن جب ملک میں جمہوریت چل رہی ہو تو باہر ہماری سیاسی پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سوائے ایک دوسرے سے لڑائی اور گروہ بندی کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان سے باہر ہم سب پاکستانی ہیں۔ اگر ادھر پاکستانی کمیونٹی کو قابل فخر بنانا ہے تو انہیں اس ملک کی سیاست میں حصہ لینا چاہئے۔ وہاں ہمارے کئی لوگ ہائوس آف لارڈز اور ہائوس آف کامنز چلے گئے ہیں تو یہ خودبخود نہیں ہوا بلکہ یہ ایک مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ میں مسلم منز آف لیبر یوکے کا چیئرمین ہوں۔ میں نے لوگوں کو متحرک کیا ہے کہ وہ وہاں کی سیاست میں حصہ لیں۔ ادھر کی سیاست میں حصہ لے کر آپ نہ صرف اس ملک کی پاکستانی کمیونٹی کی مدد کرسکتے ہیں، بلکہ آپ پاکستان کی بھی خدمت کرسکتے ہیں۔ ادھر کے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے آپ پاکستان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔
پیپلز پارٹی سے تعلق
بینظیر بھٹو جب جلا وطن تھیں، وہ بڑی تکلیف میں تھیں۔ بینظیر کا جو پہلا جلسہ گلاسکو میں ہوا، وہ میں نے کرایا تھا، اگرچہ یہ اس وقت آسان نہیں تھا اور جب بینظیر ملک کی پرائم منسٹر بن گئیں اور میں برطانوی سیاست میں داخل ہوگیا تو میرا پیپلزپارٹی بلکہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب وہ وزیراعظم بن گئیں تو شاید میں ان سے ایک دو بارملا ہوں گا لیکن جب اپوزیشن میں ہوتیں، تب میں کئی بار ان سے ملا۔ میں نے بے شک پیپلزپارٹی کو اس وقت سپورٹ کیا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی میرے تعلقات رہے ہیں۔2007ء میں بی بی پاکستان آنے سے پہلے جب گلاسکو آئیں تو میں نے اُدھر اپنے ڈیفنس سیکرٹری سے ان کی ملاقات کرائی۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان کی سیاست میں آئیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سیٹ میں نے آپ کے لیے خالی رکھی ہے۔میاں صاحبان سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کریں گے۔ سو She was very bright۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے میاں برادران سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔
والد کی جدوجہد
میرے والد صاحب کبھی سکول گئے ہی نہیں تھے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جدوجہد ہے‘ وہ ہماری جدوجہد سے بہت زیادہ ہے۔ مثلاً آپ انگریزوں کے ملک چلے جائیں‘ اور آپ کو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو‘ بلکہ اردو کا بھی ایک لفظ نہ آتا ہو‘ اور وہاں جا کر سلیز مین بن جاؤ‘ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک بیگ میں کپڑے اور مختلف چیزیں بھر لیتے تھے۔ پھر شہر سے دور دراز علاقوں میں بس یا فیری لے کر چلے جاتے تھے اور وہاں ان کے سامنے بیگ کھول کے رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ اپنی پسند اور ضرورت کی چیزیں خود اٹھا لیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ بغیر انگریزی کے یہ کام کتنا مشکل ہو گا کہ گاہکوں کو قائل کرنا اور انہیں ان کی ضرورت کی چیز دینی۔ ان گوروں کا جذبہ بھی قابل تعریف ہے کہ وہ ایسے شخص سے بھی چیزیں خرید لیتے تھے‘ جو ایک لفظ بھی نہ بول سکتے ہوں۔
سخت جان قوم
اس قوم میں ماشاء اللہ پوٹینشل بھی بہت ہے۔ ہم بہت جلد بحرانوں سے نکل آتے ہیں۔ امریکہ میں Hurricane آیا تو لوگوں کو سنبھلنے میں کئی برس لگے۔ لیکن ہمارے ہاں سیلاب آیا تو چھ مہینے کے اندر لوگوں نے چہل پہل شروع کر دی تھی۔ مکان ‘ فصلیں‘ دکان، کاروبار وغیرہ دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ قوم ایسی ہی ہے کہ جتنی بھی مشکل آئے‘ کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتی ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں سولہ سولہ، اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈشیڈنگ ہوتی ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ کوئی اور راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ زلزلہ آیا تو سال کے اندر لوگ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی
پاکستانی دنیا میں جدھر بھی گئے ہیں‘ انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ہر میدان میں اپنی قابلیت ثابت کی ہے۔